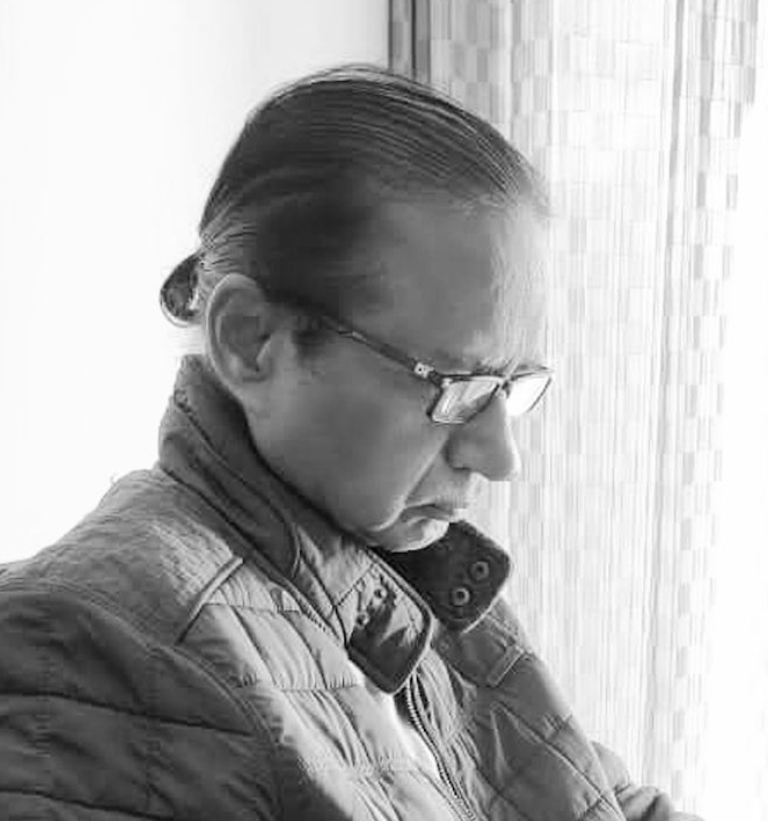برِصغیر ہی کیا، دنیا بھر میں مسلمانوں کی فکر بیشتر مذہبی تقدس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکستان سمیت۔

لیکن ایک چیز جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ برِصغیر میں مسلمانوں کی فکر کا محاورہ (ایڈیم) ’’ادبی‘‘ تھا (اس کی وضاحت آگے آئے گی)۔ وہ اِن اصطلاحات اور اس سیاق و سباق میں سوچتے تھے۔ مراد یہ کہ اگر کوئی محقق برِصغیر کے مسلمانوں کی فکر پر کام کرنا چاہتا ہے، تو اسے لگے بندھے پیمانوں کو طاق میں رکھنا ہو گا۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں برِصغیر میں مسلمانوں میں کسی فکر کا ارتقا نہیں ہوا تو اس کا یہ کہنا غلط ہو گا، کیونکہ وہ لگے بندھے پیمانوں کا اطلاق کر رہا ہو گا۔
یہاں ایک نیا پیمانہ جو میں وضع کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ برِصغیر میں مسلمانوں کی فکر کی تفہیم کے لیے مغربی فکر کے پیمانے ناکافی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مقامی فکر کے ضمن میں ہمیں مقامی پیمانے بنانے ہوں گے۔ تب ہی ہم اس نظریے سے جان چھڑا سکیں گے کہ برِصغیر میں مسلمانوں میں فکر کا ارتقا نہیں ہوا۔ اور یہاں فکر کے ارتقا سے مراد فلسفیانہ و منطقی فکر کے ساتھ ساتھ سماجیاتی و غیرسماجیاتی علومی فکر بھی مراد ہے۔
ایک بات تو فوراً میرے ذہن میں آتی ہے۔ وہ یہ کہ اب شاعری میں سے فکر کو اخذ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات ایک اصول کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ یہ بھی مغربی پیمانوں کا اثر ہے۔
سوال یہ ہے کہ شاعری میں سے فکر کو کیوں کشید نہیں کیا جا سکتا۔ جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ شاعری ہے اور اس میں مثلاً (1) متضاد و متصادم باتیں بیان ہوتی ہیں۔ (2) یہ جذبات کا مرقع ہوتی ہے۔ (3) یہ تو شاعر کی وارداتِ قلبی ہوتی ہے۔ وغیرہ۔
یعنی خاص یہ بیان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دل پہ جو گزرتی ہے، کیونکہ وہ غالباً ذہن کی بھٹی سے نہیں گزری ہوتی، اور مقدمات کی صورت اختیار نہیں کرتی، لہٰذا، وہ فکر نہیں ہو گی۔
یا کیونکہ شاعری جذبات کا مرقع ہے، باایں سبب اغلب ہے کہ اس میں مقدمات موجود نہیں ہوں گے، اور یوں یہ منطق کے معیار پر پورا نہیں اترے گی، اور فکر نہیں بن پائے گی۔
اور چونکہ شاعری کو منطق کے اصولوں اور معیارات کی کسوٹی پر جانچا نہیں جا سکتا، سو اسے فکر کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔
یہ چند اہم اعتراضات ہیں، میں نے جن کا جواب اپنی فہم کے مطابق دینے کی کوشش کی ہے۔ جو لوگ ان اعتراضات کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں، وہ اپنے اعتراضات کی مزید توضیح کر سکتے ہیں۔
اب اگر انسانوں کی کسی آبادی کی فکر کا محاورہ، ادبی و شعری ہو، اس میں ادبی نظریے اور ادبی تنقید کا اضافہ بھی لازم ہے، تو کیا اس کی فکر کو محض اس لیے فکر کا درجہ نہیں دیا جائے اور اسے مسترد کر دیا جائے گا کیونکہ یہ فکر تو فکر کے کچھ مخصوص پیمانوں پر پورا نہیں اترتی۔

گو کہ اس ضمن میں میری رائے بھی پہلے یہی ہوا کرتی تھی، پر اب میں یہاں اس رائے کو اُلانگ کر آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ فکر کسی بھی قسم کے محاورے میں تشکیل پا سکتی ہے۔ یعنی کسی بھی آبادی کا جو محاورہ اس کی فکر پر حاوی ہو گا یا اس آبادی کی فکر جس محاورے میں ظہور کر رہی ہو گی، وہ آبادی اپنا اظہار اسی محاورے میں کرتی ہو گی، اور اسی محاورے میں اس کی فکر تشکیل پائے گی۔
اس معاملے میں ہمیں وسیع المشربیت اور وسیع الذہنیت کو اپنانا چاہیے اور نہ صرف یہ کہ برصغیر کے مسلمانوں کی فکر کو ایک فکر کے طور پر دیکھنا اور سمجھنا چاہیے، بلکہ باایں انداز اسے جانچنا اور پرکھنا بھی چاہیے۔ بشمول دوسری فکروں کے۔
اوپر شروع ہی میں، میں نے مذہبی فکر کو تقدیس کے ساتھ منسلک کیا۔ مگر اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ مذہبی فکر، فکر نہیں ہوتی۔ یہ مذہبی فکر تو ہوتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی جدا اور آزاد حیثیت میں ایک فکر بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس فکر میں سے خالص فکر کو کشید کرنے کے لیے اس کی فکری ساخت اور پھر ساختیات تک پہنچنا ضروری ہے۔ یعنی اس کی منہاجیات کے اصول و قواعد کو جاننا ضروری ہے۔
عیاں رہے کہ یہ فکری ساخت، ساختیات، اور منہاجیات کے تعین کے معاملہ ادبی و شعری اور ادبی نظریے اور ادبی تنقید کے ضمن میں بھی یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ مگر جہاں تک مذہبی فکر کا تعلق ہے، تو اس میں سے تقدس کو منہا کرنے کی جو بات ہے، وہ فکری ساخت، ساختیات، اور منہاجیات کی تشکیلات کو غیرمعمولی اہمیت کا حامل بنا دیتی ہے۔
اوپر جو ایک اعتراض یہ درج ہوا کہ بالخصوص شاعری میں، یا افسانوی نثر میں بھی، یا پھر ادبی و تنقدی نثر میں بھی، متضاد و متصادم خیالات، تصورات اور نظریات بیان ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اسے فکر کا مرتبہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس ضمن میں یہ وضاحت دی جا سکتی ہے کہ اگر کہیں جیسا کہ کسی شعری فکر میں تضاد و تصادم موجود ہے، تو اسے ویسے ہی بیان کر دیا جائے۔ اس میں کیا حرج ہے؟

مگر ایک حرج ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایک ایسی فکر جسے منطق کے اصولوں پر پرکھا جا سکتا ہے، وہ تضادات و تناقضات سے مبریٰ ہو گی۔ یہ بات کہاں اور کیسے لکھی گئی! مغربی فکر کی تاریخ میں جو فلاسفہ اور مفکرین گزرے ہیں، کیا ان کی فکر کسی تضاد و تناقض سے سراسر پاک تھی؟ قطعاً نہیں۔ اور یہ جو منطقی اصول ہیں، یہ اسی چیز کو تو جانچنے کے لیے بنے ہیں کہ کسی فکر میں اگر کہیں تضاد و تناقض ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے۔
آخر میں دو مثالوں کا ذکر ضروری ہے، جو اوپر بیان کیے گئے میرے استدلال کی وضاحت کو آسان بناتی ہیں۔
پہلی مثال اقبال [1938-1877] بطور شاعر کی ہے۔ یعنی وہ اقبال جو شاعر ہیں۔ یعنی اقبال کی شاعری میں سے فکر کو اخذ و کشید کیا جانا چاہیے۔ مگر اس طرح نہیں، جس طرح اقبالیات کی فکری صنعت کے ماہرین کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جیسا کہ تقدس کا ملمع چڑھا کر۔ یا انھیں اسلامی شاعر بنا کر۔ یا ان کا جو اصل رنگ ہے، خود کو اس میں رنگ کر۔ یعنی مسلمانوں کی ’’عظمتِ رفتہ‘‘ کا کرب (اینگسٹ)۔ اس عظمتِ رفتہ کی بازیافت سے متعلق کرب۔
بلکہ اقبال بطور شاعر کو اس انداز میں سمجھنے کی ایک سعی، خواجہ منظور حسین کی کتاب، ’’اقبال اور چند دوسرے شاعر‘‘ ہے۔ (اسے میری کم علمی کہہ لیجیے کہ مزید کوششیں میری نظر میں نہیں!)
دوسری مثال محمد حسن عسکری [1978-1919] ہیں۔
میں انھیں ایک مفکر سمجھتا ہوں۔ انھوں نے ناول اور افسانے بھی لکھے۔ کالم بھی لکھے۔ ترجمہ بھی کیا۔ تنقیدی نظریے پر بھی کام کیا۔ ادبی تنقید بھی لکھی۔ ایک ناقد کے طور پر ان کا مرتبہ مسلمہ ہے۔ وہ ایک ایسے مفکر ہیں، جو ادبی نظریے اور ادبی تنقید کی جولانگاہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ان کی فکر کا محاورہ، ادبی نظریہ اور ادبی تنقید ہے۔
ریختہ پراجیکٹ پر ان کی جو مختصر سوانح دی گئی ہے، وہاں اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا گیا ہے کہ شروع میں انھوں نے ناول و افسانے لکھے، مگر پھر ان کی توجہ تنقید کی طرف کیوں مبذول ہو گئی اس کا سبب معلوم نہیں۔
میرا خیال یہ ہے کہ محمد حسن عسکری فکر و دانش کی دنیا کا ستارہ تھے، مگر وہ ایک ایسے ماحول میں موجود تھے، جہاں فکر، آزاد حیثیت میں پنپ نہیں رہی تھی، اور فکر کا جو محاورہ تھا، وہ ادبی و تنقیدی تھا۔ غالباً یہی سبب تھا کہ انھیں فکر کی طلسمِ ہوشربا (انھوں نے ’’انتخابِ طلسمِ ہوشربا‘‘ بھی تیار کیا۔) ادبی نظریے اور تنقید کی طرف کھینچ لائی۔ یہ فکر و دانش سے قریب ترین ٹھکانہ تھا۔
آخر میں ایک ضروری وضاحت۔
تنہا مغربی فکر ایک ایسی فکر ہے، جس کی تشکیل فلسفیانہ اور مطنقی محاورے میں ہوئی۔ اور ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس فکر کی نمود اصل میں مذہبی فکر سے ہوئی، اور پھر اس فکر کا آزادنہ ارتقا ممکن ہوا۔ غالباً اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اس کی پشت پر یونانی فلسفے کی کمک بھی موجود تھی۔
[عیاں رہے کہ یونانی فلسفیانہ فکر کے ڈانڈے قدیم بابلی فکر سے جا ملتے ہیں، اور یونانی فلسفیانہ فکر کوئی معجزہ نہیں، جیسا کہ کارل پاپر کا بھی خیال تھا۔ اس ضمن میں تحقیق روزافزوں ہے۔]
اس کے علاوہ جتنی اور دوسری فکریں ہیں، ان کا محاورہ مختلف و متنوع ہے۔ جیسا کہ قدیم چینی فکر، حکمت کے محاورے کی حامل ہے۔ جیسا کہ قدیم ہندی فکر اسطوری اور قدرے حکمتی محاورے پر مشتمل ہے۔
حرفِ آخر:
ضروری ہے کہ ہم اپنا رویہ تبدیل کریں، اور چیزوں کو ان کی ارتقائی کٹھالی میں رکھ کر دیکھیں، سمجھیں، اور جانچیں۔ یعنی کسی ایک پیمانے کو حتمی پیمانہ قرار دے کر فکرِ انسانی کی مختلف و متعدد تشکیلات کو محدود و مسدود نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے تعصبات سے بالاتر ہو کر کسی بھی نوع کی فکر کی فکری ساخت، اس کی ساختیات اور اس کی منہاجیات کو بھی پیشِ نظر رکھیں اور پھر اس کا محاکمہ کریں۔
[21 اکتوبر، 2025]